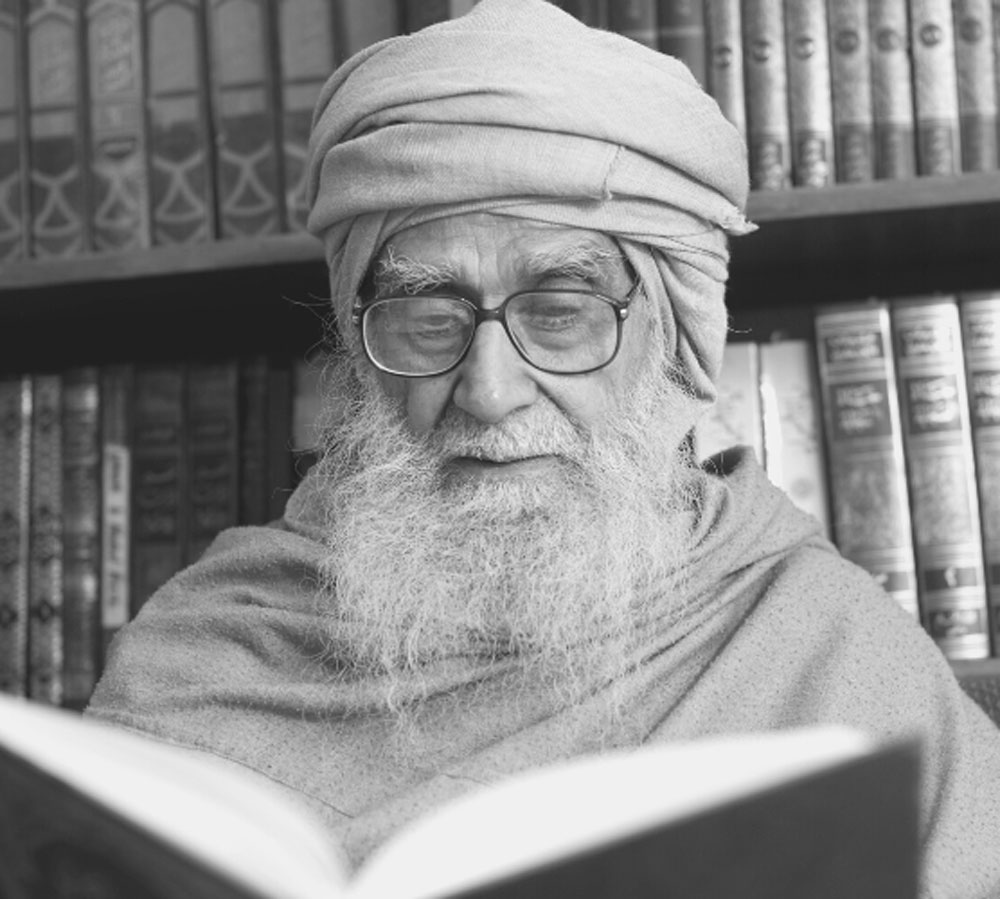فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قومی اتحاد
Communal Harmony and National Integration
بر صغیر ہند لمبی جدوجہد کے بعد ۱۵ اگست ۱۹۴۷ کو آزاد ہوا۔ یہ آزادی دو قومی نظریہ کے اصول پر ہوئی۔ تا ہم جو چیز تقسیم ہوئی وہ جغرافیہ تھا، نہ کہ قوم۔ یعنی انڈیا او رپاکستان کے نام پر دو ملک بن گئے مگردونوں قوم کے افراد دونوں حصوں میں بدستور آباد رہے۔ یہ ایک خطرناک صورت حال تھی۔ کیوں کہ قومی جھگڑے کو ختم کرنے کے نام پر ملک کو تو تقسیم کردیا گیا مگر قوم بدستور غیر منقسم رہی۔ اس طرح زمینی بٹوارہ کے باوجود نزاعی صورت حال بدستور قائم رہی، بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ۔ پہلے اگر وہ دو بے اقتدار قوموں کا جھگڑا تھا تو اب وہ دو بااقتدار ریاستوں کا جھگڑا بن گیا۔
اس مسئلہ کی نزاکت کو مہاتما گاندھی نے پہلے ہی دن محسوس کرلیا تھا۔ چنانچہ آزادی کے وقت اُنہوں نے اپنے ایک مضمون میں یہ تاریخی الفاظ لکھے تھے—ہندو ؤں اور مسلمانوں کو امن اور ہم آہنگی سے ایک ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ میں اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا:
Hindus and Musalmans should learn to live together with peace and harmony, otherwise I should die in the attempt.
سوئے اتفاق سے مہاتما گاندھی کو آزادی ہند کے جلد ہی بعد گولی مار کر ہلاک کردیا گیا۔ یہ بلاشبہہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امن و اتحاد قائم کرنے کا عمل اپنے پہلے ہی مرحلہ میں اپنے سب سے بڑے لیڈر سے محروم ہوگیا۔
جیسا کہ معلوم ہے، آزادی کے ساتھ ہی خطّ تقسیم کے دونوں طرف فرقہ وارانہ تشدد ایک بھیانک عمل کی صورت میں شروع ہوگیا۔ تشدد کا یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ آخر کار اُس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے اس مسئلہ پر ایک نیشنل کانفرنس بلائی۔ اس کااجلاس نئی دہلی میں ۲۸ ستمبر سے یکم اکتوبر ۱۹۶۱ تک جاری رہا۔ اس کانفرنس میں اتفاق رائے سے ایک آرگنائزیشن (تنظیم) کی تشکیل کی گئی جس کا نام نیشنل انٹگریشن کونسل (قومی یکجہتی کونسل)تھا۔ اس کا مرکزی دفتر نئی دہلی میں قائم کیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ وہ قومی یکجہتی سے متعلق تمام مسائل کا جائزہ لے اور ضروری سفارشیں پیش کرے۔
اس کونسل کا اجلاس دوسری بار ۲۔۳ جون ۱۹۶۲ کو نئی دہلی میں ہوا۔ شرکاء نے تقریریں کیں اور فرقہ وارانہ مسئلہ کے حل کے لیے کئی تجویزیں پیش کیں۔ مگر ان تجویزوں پر کوئی عمل نہ ہوسکا۔ یہاں تک کہ دوبارکے بعد اس کونسل کاکوئی تیسرا اجلاس جواہر لال نہرو کی زندگی میں نہیں ہوا۔
اس کے بعد جب اندرا گاندھی ملک کی وزیر اعظم بنیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ نیشنل انٹگریشن کونسل کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اُنہوں نے ۲۰۔۲۱ جون ۱۹۶۸ کو سری نگر میں تنظیم کا اجلاس بُلایا۔ یہاں تفصیلی بحثیں ہوئیں۔ آخر کار ایک مکمل لائحہ عمل ترتیب دیاگیا۔ اس کا ایک حصّہ یہ تھا:
فرقہ وارانہ سرگرمی کے معنیٰ یہ قرار دیے جائیں کہ ہر وہ فعل جو مختلف مذہبی فرقوں، یا نسلی گروپوں یا ذاتوں یا برادریوں کے درمیان مذہب، نسل، ذات پات یا برادری کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر دشمنی یا نفرت پھیلائے یا پھیلانے کی کوشش کرے۔ یہ جرم قابلِ دست اندازی پولیس ہو اور اُس کے تحت سزا پانے والے کو عوامی نمائندگی کے قانون کے تحت نااہل قرار دے دیاجائے۔ افواہ پھیلانا یا گھبرادینے والی خبریں اور افکار کی اشاعت کو دفعہ ۱۵۳ (اے) کے تحت جرم قرار دے دیا جائے۔
کونسل کے جلسوں میں اس قسم کی بہت سی تجویزیں اتفاق رائے کے ساتھ پاس کی گئیں۔ اُس کے بعد اُس کی تائید میں بہت سے قانون اور ضابطے بنائے گئے۔ مگر عملاً ان کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے ملک کی حقیقی صورت حال اب بھی تقریباً وہی ہے جیسی کہ وہ ۱۹۴۷ میں تھی۔
اس ناکامی کا سبب کیا ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس مسئلہ کو سادہ طورپر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سمجھ لیاگیا۔ مگر اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے یہ مسئلہ لااینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں۔ وہ ذہنی تعمیر یا شعوری بیداری کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے اصل ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کوایجوکیٹ کیا جائے۔ اُن کے اندر صحیح سوچ پیدا کی جائے۔ اُن کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ ایک چیز اور دوسری چیز کے فرق کو سمجھیں۔ وہ نتیجہ خیز عمل اور بے نتیجہ عمل کے درمیان تمیز کرنا جانیں۔ وہ یہ جانیں کہ اُنہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ عملی اقدام سے پہلے سوچنے کے مراحل کی تکمیل ضروری ہوتی ہے۔ عمل کو سوچ کے تابع ہونا چاہئے، نہ کہ سوچ کو عمل کے تابع بنا دیا جائے۔
اس قسم کا باشعور سماج گویا کہ وہ زمین ہے جہاں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فصل اُگائی جاسکتی ہے۔ قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سماج کے استثنائی بگاڑکو جرّاحی جیسے عمل کے ذریعہ درست کیا جائے۔ کوئی بھی قانون سماج کی عمومی حالت کی اصلاح کے لیے نہیں ہوتا۔ جرّاحی کا عمل جسم کی ایک جزئی بیماری کو شفا دینے کے لیے ہوتاہے۔ اگر پورا جسم عمومی طورپر مرض کا شکار ہوجائے تو ایسی حالت میں جرّاحی کے عمل کاکوئی فائدہ نہیں۔
یہاں میں اس مسئلہ کے چند بنیادی پہلوؤں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلو براہِ راست طورپر عوام کی ذہنی تشکیل کے سوال سے تعلق رکھتے ہیں۔ بے حد ضروری ہے کہ ان سوالات کا واضح جواب ہمارے ذہن میں ہو تاکہ کسی کنفیوژن کے بغیر ذہنی تشکیل یا شعوری تعمیر کا کام عمل میں لایا جاسکے۔
مذہبی اختلاف
اس سلسلہ میں پہلا نظری مسئلہ وہ ہے جو مذہبی اختلاف سے تعلق رکھتا ہے۔ مذاہب کا تقابلی مطالعہ بظاہر یہ بتاتا ہے کہ مذاہب کے درمیان واضح اختلافات پائے جاتے ہیں۔ مثلاً کسی مذہبی گروہ کا عقیدہ وحدتِ وجود(monism) کے تصور پر قائم ہے اور کسی گروہ کا عقیدہ توحید(monotheism) کے تصور پر قائم ہے۔ کسی مذہب میں خود دریافت کردہ سچائی (self-discovered truth) کا تصور ہے اور کسی مذہب میں الہامی سچائی(revealed truth)کا۔
کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مذہبی فرق و اختلاف ہی تمام فرقہ وارانہ نزاعات کی اصل جڑ ہے۔ ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی صرف اُس وقت پیدا کی جاسکتی ہے جب کہ کسی نہ کسی طرح ان مذہبی اختلافات کا خاتمہ کردیا جائے۔ کچھ انتہا پسند لوگ، اُن کو بلڈوز کردو(buldose them all) کی زبان بولتے ہیں۔ مگر وہ اتنی زیادہ ناقابلِ عمل ہے کہ وہ سرے سے قابلِ تذکرہ ہی نہیں۔ کچھ دوسرے لوگ یہ کوشش کررہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ تمام مذاہب کی تعلیمات ایک ہیں۔
اس دوسرے گروہ میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر بھگوان داس (1869-1958) کا ہے۔ وہ نہایت قابل آدمی تھے۔ اُنہوں نے تمام بڑے بڑے مذاہب کے لمبے مطالعہ کے بعد ایک کتاب تیار کی جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ تمام مذاہب کی تعلیم ایک ہے۔ یہ کتاب ۹۲۹ صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا نام یہ ہے:
Essential Unity Of All Religions
منتخب اقتباسات کو لے کر ہر مذہب کو ایک ثابت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مختلف ملکوں کے دستور کو لے اور پھر ہر دستور سے کچھ منتخب دفعات کو جمع کر کے ایک کتاب چھاپے اور اُس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرے کہ ہر ملک کا دستور ایک ہے اور ایک ہی قسم کی دفعات کا مجموعہ ہے۔ اس قسم کا آفاقی دستور کسی مصنف کو تو خوش کرسکتا ہے مگر وہ کسی ایک ملک کے لیے بھی قابلِ قبول نہ ہوگا۔ ہر ملک اس کو شکر یہ کے ساتھ رد کردے گا۔ یہی معاملہ اتحاد مذہب کے بارہ میں مذکورہ قسم کی کتابوں کا ہے۔ اس قسم کی کتاب اُس کے مرتب کو خوش کرسکتی ہے مگر وہ اہلِ مذاہب کے لیے قابلِ قبول نہیں ہوسکتی۔
میں نے بھی اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے۔ میں نے اپنے مطالعہ میں پایا ہے کہ تمام مذ۱ہب کو ایک بتانا واقعہ کے مطابق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مختلف مذاہب میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ اُن کو ایک ثابت کرنا عملی طورپر ممکن ہی نہیں۔ مثلاً کسی مذہب کا کہنا ہے کہ خدا ایک ہے۔ کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا دو ہیں۔ کوئی مذہب بتاتا ہے کہ خدا تین ہیں اور کسی مذہب کادعویٰ ہے کہ خداؤں کی تعداد ۳۳ یا ۳۳کروڑ ہے۔ کسی کے نزدیک خداؤں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اُن کی گنتی ہی ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں ہر مذہب کی تعلیم کو ایک بتانا ایک ایسا بیان ہے جوکسی خوش فہم کے دماغ میں تو جگہ پاسکتا ہے مگر عملی اور منطقی طورپر اس کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔
حتیٰ کہ بالفرض کسی تدبیر سے تمام مذاہب کے ٹیکسٹ کو ایک ثابت کردیاجائے تب بھی اختلاف ختم نہ ہوگا۔ کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں ہر ایک کا ایک تسلیم شدہ ٹیکسٹ ہے مگر اس ٹیکسٹ کی تعبیر میں دوبارہ اختلافات پیدا ہوجاتے ہیں اور ایک مذہبی ٹیکسٹ خود داخلی طورپر کئی مذہبی فرقے (sects) وجود میں لانے کا سبب بن جاتا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اختلاف یا فرق صرف مذہب کی بات نہیں۔ ہماری دنیا پوری کی پوری فرق اور تنوع کے اصول پر قائم ہے۔ یہ فرق اتنا زیادہ ہمہ گیر ہے کہ کوئی بھی دو چیز یا کوئی بھی دو انسان فرق سے خالی نہیں۔ کسی نے بجا طورپر کہا ہے کہ فطرت یکسانیت سے نفرت کرتی ہے:
Nature abhors uniformity
جب فرق و اختلاف خود نیچر کا ایک قانون ہو تو مذہب اُس سے مستثنیٰ کیوں کر ہوسکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی تمام چیزوں میں ایک اور دوسرے کے درمیان فرق پایا جاتا ہے اسی طرح مذاہب میں بھی ایک اور دوسرے کے درمیان فرق ہے۔ دوسرے معاملات میں ہم نے فرق کو مٹانے کی ضروری کوشش نہیں کی بلکہ یہ کہہ دیا کہ آؤ ہم اس پر اتفاق کرلیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ہے:
Let us agree to disagree
یہی عملی فارمولا ہمیں مذہب کے معاملہ میں بھی اختیار کرنا چاہئے۔ یہاں بھی ہمیں فرق و اختلاف کے باوجود اتحاد پر زور دینا چاہئے، نہ کہ فرق و اختلاف کے بغیر اتحاد پر۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہبی اختلافات کے مسئلہ کا حل صرف ایک ہے او روہ ہے—ایک کی پیروی کرو اور سب کا احترام کرو:
Follow one and respect all
کلچر کا اختلاف
اس سلسلہ میں دوسرا مسئلہ کلچر کا اختلاف ہے۔ مختلف گروہوں کے درمیان کلچر کا اختلاف ایک حقیقت ہے۔ کچھ لوگوں کاخیال ہے کہ یہی اختلاف تمام نزاعات کی جڑ ہیں۔ اُن کے نزدیک اس مسئلہ کا حل یہ ہے کہ کلچر کے نام پر جو اختلافات سماج میں پائے جاتے ہیں اُن کو یکسر مٹادیا جائے اور ایسا سماج قائم کیا جائے جس کے اندر کلچرل یونٹی ہو۔
یہ تجویز بھی سراسر غیر عملی ہے۔ کلچر نہ کسی کے بنانے سے بنتا اورنہ کسی کے مٹانے سے مٹ جاتا۔ کلچر ہمیشہ تاریخی عوامل کے تحت لمبی مدت کے درمیان بنتا ہے۔ کسی دفتر میں بیٹھ کر کلچر کا نقشہ نہیں بنایا جاسکتا۔
دوسری عالمی جنگ کے بعد کئی ملکوں میں ایسے نظریہ ساز (idealogue) پیدا ہوئے جنہوں نے قومی اتحاد کے لیے ایک کلچر کا سماج بنانے پر زور دیا۔ مثلاً کناڈا میں اسی نظریہ کے تحت یونی کلچرل ازم کی تحریک چلائی گئی۔ مگر تجربہ نے بتایا کہ یہ قابلِ عمل نہیں۔چنانچہ بیس سال کے اندر ہی اندر اس نظریہ کو ترک کر دیا گیا۔اب کناڈا میں سرکاری طورپر ملٹی کلچرلزم کے اصول کواختیار کر لیا گیا ہے اور یونی کلچرلزم کے نظریہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا گیاہے۔
یہی معاملہ امریکا کا ہے۔ امریکا میں دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکنائزیشن کی تحریک چلائی گئی۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا۔ مگر لمبی جدوجہد کے بعد معلوم ہوا کہ وحدت کلچر کایہ نظریہ قابلِ عمل نہیں۔ چنانچہ اس نظریہ کو ترک کر دیا گیا اور امریکا میں بھی ملٹی کلچرلزم کے اصول کو اختیار کرلیا گیا۔
حقیقت یہ ہے کہ کلچر کا اختلاف دوگروہوں کے درمیان اختلاف کا معاملہ نہیں ہے۔ خودایک گروہ کے درمیان بھی یہ اختلاف پایا جاسکتاہے۔ اس داخلی اختلاف کی مثالیں ہر گروہ میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس لیے مختلف مذاہب کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی لانے کے لیے مذہبی تعلیمات میں تبدیلی ضروری نہیں۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ اہل مذاہب کے اندر وہ سوچ پیدا کی جائے جس کو جیو اور جینے دو (live and let live) کہا جاتاہے۔
کچھ لوگ اس ناکام تجربہ کو اب بھی دوہرانا چاہتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے سوشل ری انجینیرنگ رکھ دیا ہے:
Social re-engineering of Indian Society
اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے مختلف گروہوں میں کلچر کے اعتبار سے جو فرق پایا جاتا ہے اس کی دوبارہ تشکیل دی جائے اور ایسا سماج بنایا جائے جس میں کلچر کا فرق ختم کردیا گیا ہو اور ملک کے تمام لوگ ایک ہی مشترک کلچر کے مطابق زندگی گزاریں۔
یکساں کلچر بنانے کے کام کو جوبھی نام دیا جائے، نتیجہ بہر حال سب کا ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ اس قسم کا نظریہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کلچرل بلڈوزنگ ہے۔ اس کو خواہ سوشل ری انجینئرنگ کہا جائے یا کلچرل نیشنلزم، وہ بہر حال ناقابلِ عمل ہے۔ اور جو چیز فطری قوانین کے مطابق، سرے سے قابلِ عمل ہی نہ ہو اس کو اپنے عمل کا نشانہ بنانا صرف اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔
اس معاملہ میں میرا اختلاف نظریاتی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عملی بنیاد پر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ ناقابلِ عمل ہے۔ اگر بالفرض ایسا ممکن ہوتا کہ پورے ملک کی ایک زبان ایک کلچر، رہن سہن کا ایک طریقہ بن جائے تو میں کہتا کہ ضرور ایسا کرنا چاہئے۔ مگر فطرت اور تاریخ کے قوانین کے اعتبار سے ایسی یکسانیت ممکن ہی نہیں۔ نہ کبھی وہ ماضی میں ممکن ہوئی ہے اور نہ وہ مستقبل میں ممکن ہو سکتی ہے۔ کلچر ہمیشہ خود اپنے قوانین کے تحت بنتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ کسی دفتر میں کلچر کا ایک خود پسند نقشہ بنایا جائے اور اس کو ملک کے تمام گروہوں میں رائج کردیا جائے۔
ایسی حالت میں ہم کو وہی کرنا چاہئے جو ہم دوسرے اختلافی معاملات میں کرتے ہیں، یعنی رواداری (tolerance) کے اصول پر اپنے مسئلہ کو حل کرنا۔ حقیقتِ واقعہ سے ہم آہنگی کا طریقہ اختیار کرکے اس سے نپٹنا، نہ کہ اس سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کرنا۔اس معاملہ میں ٹکراؤ کا طریقہ صرف مسئلہ کو بڑھانے والا ہے نہ کہ اس کو حل کرنے والا۔
یہاں ایک اور بات کی وضاحت ضروری ہے۔کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندو تو انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفاداری کے مراکز اسی ملک میں ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مسلمانوں کے اعتقادی مراکز (مثلاً مکہ اور مدینہ) انڈیا سے باہر ہیں۔ اس لیے مسلمان کبھی اس ملک کے وفادار نہیں ہوسکتے۔
میں کہوں گا کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق ہندو اور مسلمان دونوں سے ہے۔ مثلاً ایک ہندو اگر سومناتھ کے مندر سے عقیدت رکھتا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اجودھیا کے مندر کا عقیدت مند نہیں ہو سکتا۔ ایک ہندو کے دل میں اگر اپنی ماں کی محبت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا دل باپ کی محبت سے خالی ہوگا۔
یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلمان اگر مکہ اور مدینہ سے قلبی لگاؤ رکھتاہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو انڈیا سے قلبی لگاؤ نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی سوچ انسان کی تصغیر (underestmation) ہے۔ کوئی شخص ہندو ہو یا مسلمان دونوں حالتوں میں وہ فطرت کا ایک مظہر ہے اور فطرت نے جو انسان پیدا کیا ہے اُس کے اندر اتنی وسعت موجود ہے کہ وہ بیک وقت کئی محبتوں اور وفاداریوں کو یکساں طورپر اپنے دل میں جگہ دے سکے۔
یہ ایک ایسی فطری حقیقت ہے جس کا تجربہ ہر انسان کررہا ہے۔ ہر مرد اور عورت خود اپنے ذاتی تجربہ کے تحت اس کو جانتے ہیں۔ اس فطری حقیقت کو ایک مغربی مفکر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے— میرے اندر اتنی زیادہ وسعت ہے کہ میں مختلف تضادات کو بیک وقت اپنے اندر جگہ دے سکوں:
I am large enough to contain all these contradictions.
مذہب اور سیاست
فرقہ وارانہ جھگڑوں میں اکثر مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی یاقومی چیز مذہبی ایشو بن جاتی ہے اور پھر تیزی سے لوگوں کے جذبات بھڑک اُٹھتے ہیں جو مختلف فرقوں کے درمیان متشددانہ ٹکراؤ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس بنا پر بہت سے لوگ خود مذہب کے مخالف بن گئے ہیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ انسان کو مذہب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے مذہب کا خاتمہ کردینا چاہئے۔اس کے بغیر سماجی اتحاد ممکن نہیں۔
مگر یہ ایک انتہا پسندی کے جواب میں دوسری انتہا پسندی ہے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ سیکولر انتہا پسندی سے کرنا ہے جو نہ تو ممکن ہے اور نہ مفید۔ اصل یہ ہے کہ مذہب بذاتِ خود کوئی مسئلہ نہیں۔ مذہب انسانی زندگی کا ایک صحت مند حصہ ہے۔ جو چیز مسئلہ ہے وہ کچھ مفاد پرست لوگوں کی طرف سے مذہب کا سیاسی ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس لیے اصل کام ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا ہے نہ کہ خود مذہب کو۔
مذہب کے دو حصے ہیں—انفرادی اوراجتماعی۔ مذہب کے انفرادی حصہ سے مراد عقیدہ اور عبادت اور اخلاق اور روحانیت کاحصہ ہے۔ اور اجتماعی حصہ سے مراد اُس کے سیاسی اور سماجی احکام ہیں۔ اس معاملہ میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ عام حالات میں صرف مذہب کے انفرادی حصہ پر زور دیا جائے۔ ساری توجہ مذہب کی روح زندہ کرنے پر لگائی جائے۔
جہاں تک مذہب کے سماجی اور سیاسی احکام کا معاملہ ہے، اُس کو اُس وقت تک نہ چھیڑا جائے جب تک پورا معاشرہ اُس کے لیے سازگار نہ ہوجائے۔ سماجی اور سیاسی احکام پورے سماج کی اجتماعی رضامندی سے قائم ہوسکتے ہیں۔ اس لیے ایسے احکام کے معاملہ میں کسی عملی اقدام سے اُس وقت تک بچنا چاہئے جب تک پورے سماج کا اجتماعی ارادہ اُس کی موافقت میں نہ ہوجائے۔
اس معاملہ کو مذہب او ر سیاست کے درمیان عملی تفریق کہا جاسکتا ہے۔ یعنی نظری طورپر سیاست کو مذہب کا حصّہ مانتے ہوئے عملی حقائق کی بنا پر سیاسی احکام کے عملی نفاذ کو موخر یا ملتوی کردیا جائے۔ اسی کا نام حکمت ہے۔ اس حکمت کا یہ فائدہ ہے کہ مذہب اور سیاست دونوں کے تقاضے پورے ہوجاتے ہیں۔ مذہب کے تقاضے حال میں، اور سیاست کے تقاضے مستقبل میں۔ اس کے برعکس اگر اس حکمت کو ملحوظ نہ رکھا جائے اور دونوں پہلوؤں کو بیک وقت اُبھار دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مذہبی تقاضے اور سیاسی تقاضے دونوں ہی پورے ہونے سے رہ جائیں۔
نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کا فرق
کمیونل ہارمنی کا سوال بنیادی طورپر نارتھ انڈیا کا سوال ہے۔ ساؤتھ انڈیا میں آج بھی کمیونل ہارمنی پوری طرح پائی جاتی ہے۔ کمیونل ہارمنی یا نیشنل انٹگریشن کے نام سے ہم جیسا سماج بنانا چاہتے ہیں وہ سماج بر وقت ہی ساؤتھ انڈیا میں موجود ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، فرقہ وارانہ جھگڑوں کے تقریباً تمام واقعات نارتھ انڈیا کے علاقہ میں ہوتے ہیں۔ جہاں تک ساؤتھ انڈیا کا تعلق ہے، وہاں فرقہ وارانہ جھگڑے اتنے کم ہیں کہ وہ کسی گنتی میں نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فرق کا مطالعہ ہمارے لیے ایک رہنما مطالعہ بن سکتا ہے۔
مزید یہ کہ خود نارتھ انڈیا کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک شہری علاقہ اور دوسرا دیہات کا علاقہ۔ واقعات بتاتے ہیں کہ بیشتر فرقہ وارانہ جھگڑے شہروں میں ہوئے ہیں یا ہوتے ہیں۔ جہاں تک دیہات کے علاقہ کا تعلق ہے، وہاں شاذونادر ہی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ اس فرق کا مطالعہ بھی بے حد اہم ہے۔ اس سے ہمیں نہ صرف واقعات کی توجیہہ میں مدد ملتی ہے بلکہ یہ فیصلہ کرنا بھی آسان ہوجاتا ہے کہ فرقہ وارانہ نزاعات کو ختم کرکے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا ماحول پیدا کرنا ان تدابیر کے ذریعہ ممکن ہے۔
قومی یکجہتی کے سلسلہ میں ہندوؤں کے کچھ عقائد ہیں جن سے مسلمانوں کو شکایت ہے۔ یہاں میں ان سے بحث نہیں کروں گا۔ اس معاملہ میں میرا مشورہ مسلمانوں کو یہ ہے کہ وہ اسلامی اصول کے مطابق اعراض اور رواداری (avoidance and tolerance) کا طریقہ اختیار کریں۔ البتہ کچھ شکایتیں یا غلط فہمیاں ہندوؤں کو مسلمانوں کے بارے میں ہیں۔ یہاں میں اس دوسرے مسئلہ کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور کچھ اسلامی اصطلاحات کی تشریح کرناچاہتا ہوں جو دونوں فرقوں کے درمیان غلط فہمی کا باعث ہیں یا باعث بن سکتی ہیں۔
یہاں میں ضمناً ایک بات کہوں گا۔ ہمارے یہاں عام رواج یہ ہے کہ مسلمان کوئی غلطی کریں تو ہندو اس کے خلاف لکھتے اور بولتے ہیں۔ اسی طرح ہندو اگر کوئی غلطی کریں تو مسلمان اُس کے خلاف لکھتے اور بولتے ہیں۔ یہ طریقہ اصلاح کے نقطۂ نظر سے بالکل بے فائدہ ہے۔ ایسی باتوں کو ایک فریق اپنی وکالت سمجھ کر خوش ہوگا مگر دوسرا فریق اُس سے کوئی مثبت اثر نہ لے گا۔
اس کے برعکس صحیح اور مفید طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اگر غلطی کریں تو خود مسلمانوں کے علماء اور دانشور اس کے خلاف بولیں اور لکھیں۔ اسی طرح ہندو اگر کوئی غلطی کریں تو ہندوؤں کے ذمہ دار اس کے خلاف لکھیں اور بولیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے کسی گھر کا کوئی لڑکااگر غلطی کرے تو سب سے پہلے اُس کا اپنا باپ اُس کی تنبیہہ کرتا ہے۔ باپ اس کا انتظار نہیں کرتا کہ محلہ کے لوگ آکر اس کے خلاف بولیں۔ اور اگر محلہ کے لوگ آکر اس کے خلاف بولیں تو بچہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔
یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ اپنوں کی تنبیہہ کو آدمی مثبت ذہن سے سنتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔اس کے برعکس غیر کی تنبیہہ کو وہ وقار کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وہ اس کا کوئی مثبت اثر قبول نہیں کرتا۔ فرقہ وارانہ اتحاد کے سلسلہ میں اس حکمت عملی کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔
قوم اور قومیت
اس سلسلہ میں چند اسلامی اصطلاحیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ان اصطلاحوں کا صحیح مفہوم مسلم اور غیر مسلم کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کرتا ہے اور ان اصطلاحوں کا غلط مفہوم برعکس طورپر دونوں کے درمیان دوری کا سبب بن جاتا ہے۔
ان میں سے ایک قومیت کا مسئلہ ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنے غیر مومن مخاطبین کو اے میری قوم، (یا قومی) کے لفظ سے خطاب کیاہے۔ اس قرآنی بیان کے مطابق، مومن اور غیر مومن کی قومیت (نیشنلیٹی) ایک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیت کا تعلق مذہب سے نہیں ہے بلکہ وطن سے ہے۔ مذہبی اشتراک کو بتانے کے لیے ملّت کا لفظ بولا جائے گا اور وطنی اشتراک کو بتانے کے لیے قومیت کا لفظ۔ موجودہ زمانہ میں وطن (home land) کو قومیت کی بنیاد سمجھا جاتاہے۔ اسلام کا اصول بھی یہی ہے۔ اسلام کے مطابق، بھی وطن ہی قومیت کی بنیاد ہے۔
اس اعتبار سے دو قومی نظریہ ایک غیر اسلامی نظریہ ہے۔ دو قومی نظریہ مسلمانوں میں یہ ذہن پیدا کرتا ہے کہ ہم الگ قوم ہیں اور دوسرے لوگ الگ قوم۔ جب کہ صحیح اسلامی ذہن یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو دوسروں کا ہم قوم سمجھیں، وہ دوسروں کو اے میری قوم کے لوگو، کہہ کر خطاب کرسکیں، جیسا کہ تمام پیغمبروں نے کیا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اور تم کو شعوب اور قبائل میں تقسیم کردیاتاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو (الحجرات ۱۳) اس آیت میں شعب سے مراد وطنی اشتراک سے بننے والی قوم ہے اور قبیلہ سے مراد نسلی اشتراک سے بننے والا گروہ۔ قرآن کے مطابق، یہ دونوں قسم کی گروہ بندی صرف تعارف کے لیے ہے، وہ عقیدہ یا مذہب کے رشتہ کو بتانے کے لیے نہیں۔
۱۹۴۷ سے پہلے کے دور میں مولانا حسین احمد مدنی نے کہا تھا کہ ’’فی زمانہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں‘‘۔ مولانا موصوف کا یہ بیان بجائے خوددرست تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اُس میں فی زمانہ (موجوہ زمانہ) کی شرط درست نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم ہمیشہ وطن ہی کی بنیاد پر تشکیل پاتی رہی ہے۔ موجودہ زمانہ میں صرف یہ ہوا ہے کہ دوسری بہت سی چیزوں کی طرح، اس معاملہ میں بھی تعین اور تشخص کے لیے جدید طریقے استعمال کئے گئے۔ مثلاً پاسپورٹ میں قومیت کا اندارج، جب کہ پہلے پاسپورٹ کا طریقہ رائج نہ تھا، بین اقوامی حقوق کے تعیّن کے لیے قومیت کی قانونی تعریف، ملک کی نسبت سے کسی قوم کے افراد کے حقوق کو قانون کی زبان میں متعین کرنا، وغیرہ۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ قوم کا لفظ موجودہ زمانہ میں بھی اصلاً اسی معنٰی میں بولا جاتا ہے جس معنٰی میں وہ قدیم زمانہ میں بولا جاتا تھا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے وہ مجمل مفہوم میں بولا جاتا تھا اور اب وہ مفصل مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔
کچھ لوگ قومیت کی تشریح انتہا پسندانہ انداز میں کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ قومیت کو مذہب کے ہم معنٰی بنا دیتے ہیں، مگر یہ ایک نظریاتی انتہا پسندی ہے۔ اس قسم کی نظریاتی انتہا پسندی کی مثالیں خود مذہب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً موجودہ زمانہ میں کچھ مسلم مفکرین نے اسلام کی تشریح ایسے انتہا پسندانہ انداز میں کی کہ اسلام کے سوا ہر نظام طاغوتی نظام بن گیا۔ کسی مسلمان کے لیے اس طاغوتی نظام میں موافقت کرکے رہنا حرام قرار پاگیا۔ حتی کہ اس مفروضہ طاغوتی نظام میں تعلیم حاصل کرنا، سرکاری ملازمت کرنا، ووٹ دینا، نزاعات کے قانونی تصفیہ کے لیے ملکی عدالت سے رجوع کرنا، سب کا سب حرام قرار پاگیا۔
طاغوتی نظام کا یہ نظریہ بعض افراد کے انتہا پسندانہ ذہن کی پیداوار تھا، اُس کا خدا و رسول والے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حقائق نے اس نظریہ کے وابستگان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی عملی زندگی میں اس سے دست بردار ہوجائیں۔ چنانچہ اب یہ تمام لوگ بلا اعلان عملی طور پر اس انتہا پسندانہ نظریہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہی معاملہ قومیت کا بھی ہے۔ مغرب کے کچھ انتہا پسند مفکرین نے قومیت کو توسیع دے کر مکمل مذہب کے روپ میں پیش کیا۔ مگر حقائق کی چٹان سے ٹکرا کر یہ نظریہ ٹوٹ کر ختم ہوگیا۔ اب عملی طور پر قومیت کا تصور تقریباً اسی فطری معنی میں بولا جاتا ہے جس فطری معنٰی میں وہ قرآن کے اندر استعمال ہوا تھا۔
بیسویں صدی کے نصف اوّل میں اُٹھنے والے مسلم رہنما اس فرق کو سمجھ نہ سکے۔ اُنہوں نے قومیت اور وطنیت کے معاملہ میں اس غیر فطری انتہا پسندی کو اصل سمجھ لیا اور اس بنا پر اُس کے غیر اسلامی ہونے کا اعلان کردیا۔ اس کی ایک مثال مشہور مسلم شاعر اقبال (وفات ۱۹۳۸) کی ہے۔ انہوں نے قومیت اور وطنیت کے اس انتہا پسندانہ وقتی تصور کو اصل سمجھ کر اُس کے بارہ میں یہ اشعار کہے تھے:
اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اُس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
قومیت اور وطنیت کے بارہ میں یہ نظریہ بلا شبہہ بے بنیاد ہے۔ عجیب بات ہے کہ اُس دور کے اکثر مسلم علماء اور دانشوروں نے سیاسی نوعیت کی چیزوں کو مذہب یا اسلام کے لیے موت و حیات کا مسئلہ سمجھ لیا۔ حالاں کہ کوئی بھی سیاسی اُتار چڑھاؤ مذہب اسلام کی ابدیت کے لیے چیلنج نہیں بن سکتا۔ مثلاً بیسویں صدی کے آغاز میں ترکی کی عثمانی سلطنت ٹوٹی تو شبلی نعمانی نے یہ شعر کہا:
زوال دولتِ عثماں زوالِ شرع و ملت ہے عزیز و فکرِ فرزند و عیال و خانماں کب تک
یہ تصور یقینی طورپر بے بنیاد ہے کہ کسی حکومت کا ٹوٹنا ’’شرع و ملّت‘‘ کے لیے زوال کے ہم معنیٰ ہے۔ ایسا نہ کبھی ہوا اور نہ ایسا کبھی ہوسکتا۔ دور اول میں خلافتِ راشدہ ٹوٹی مگر اسلام کی پُر امن توسیع مسلسل جاری رہی۔ اس کے بعد اموی سلطنت ٹوٹی تب بھی اسلام کا سفر بدستور جاری رہا، اس کے بعد عباسی سلطنت ٹوٹی، اندلس کی مسلم سلطنت ٹوٹی، مصر کی فاطمی سلطنت ٹوٹی، ہندستان کی مغل سلطنت ٹوٹی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر سلطنتوں کا یہ زوال اسلام کے زوال کا سبب نہ بن سکا۔
اسی طرح بیسویں صدی میں کئی انتہا پسندانہ نظریات اُبھرے۔ مثلاً کمیونزم، نازی ازم، نیشنلزم اور وطنیت، وغیرہ۔ مگر ان سب کا آخری انجام یہ ہوا کہ فطرت کا قانون اُن کے انتہا پسندانہ عناصر کو رد کرتا ہے اور آخر کار جو چیز بچی وہ وہی تھی جو قانونِ فطرت کے مطابق مطلوب تھی۔ فطرت کا ابدی قانون ہر دوسری چیز پر بالا ہے۔ فطرت کا قانون اپنے آپ یہ کرتا ہے کہ وہ غیر معتدل افکار کو رد کرکے اُنہیں میدانِ حیات سے ہٹا دیتا ہے اور اُن کے بجائے معتدل افکار کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔
کفر اور کافر کا تصور
اسی طرح اس معاملہ میں ایک متعلق اصطلاح کفر کی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں کفر اور کافر کا جوتصور پایا جاتا ہے وہ قومی یکجہتی کی راہ میں ایک مستقل رکاوٹ ہے۔ مگر یہ خیال ایک غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔
کفر کے لفظی معنٰی انکار کے ہوتے ہیں اور کافر کا مطلب ہے، انکار کرنے والا۔ یہ دونوں الفاظ قرآن میں پیغمبر کی نسبت سے بولے گئے ہیں، وہ عام لوگوں کی نسبت سے نہیں بولے گئے۔ مزید یہ کہ کفر یاکافر ایک شخصی کردار ہے۔ وہ کسی گروہ کا نسلی یا وراثتی نام نہیں۔ کفر یا انکار کا تحقق کسی کے بارہ میں اُس وقت ہوتا ہے جب کہ اُس کے اوپر پیغمبرانہ قسم کی دعوت جاری کی جائے اور اُس کو تکمیل کی حد تک پہنچایا جائے جس کو اتمامِ حجت کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی پیغمبرانہ دعوت کے بغیر کسی کے بارہ میں یہ کہنا درست نہیں کہ اُس نے کفر یا انکار کا فعل کیا ہے۔
اسی طرح کسی فرد یا مجموعۂ افراد کے بارہ میں متعین اور مشخص طورپر یہ اعلان کرناکہ وہ کافر ہوچکے ہیں، عام لوگوں کے لیے جائز نہیں۔ کفر کے فعل کاتعلق حقیقتاً نیت سے ہے اور نیت کا حال صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے متعین اور مشخص طورپر کسی کے بارے میں یہ اعلان کرنا کہ وہ کافر ہوگیا ہے، یہ خالصتاً اللہ کا کام ہے یا اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر پیغمبر کا۔ چنانچہ قرآن میں صرف ایک ایسا حوالہ ہے جب کہ قدیم زمانہ کے کچھ لوگوں کو متعین طورپر کافر قرار دے کر کہا گیا کہ: قل یا ایہا الکافرون (الکافرون ۱)۔ اس انداز کا مشخص خطاب قرآن میں کسی بھی دوسرے گروہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ یعنی قرآن میں اس ایک استثناء کو چھوڑ کر فعلِ کفر کا ذکر تو ہے مگر مشخص طورپر کسی کو فاعلِ کفر کا درجہ نہیں دیا گیا۔
دار الحرب کی اصطلاح
دار الحرب کی اصطلاح دورِ عباسی میں بننے والی فقہ میں ضرور استعمال ہوئی ہے مگریہ اصطلاح قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں۔ یہ فرق واضح کرتا ہے کہ دار الحرب کی اصطلاح ایک اجتہادی اصطلاح ہے، وہ کوئی منصوص اصطلاح نہیں۔ اور جو نظریہ اجتہادی ہو اُس کے بارہ میں یہ ثابت ہے کہ وہ صحیح بھی ہوسکتا ہے اور غلط بھی۔
میرے نزدیک دار الحرب کی اصطلاح ایک اجتہادی خطا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہر قسم کے واقعات پیش آئے۔ مگر آپ نے کسی بھی علاقہ کو دار الحرب قرار نہیں دیا۔ اگر قرآن وسنت میں اجتہاد کرکے اس سلسلہ میں کوئی اصطلاح بنائی جائے تو وہ صرف ایک ہوگی، اور وہ دار الدعوہ ہے۔ یہی اسلامی روح کے مطابق ہے۔ اسلام ہر قوم کو مدعو کی نظر سے دیکھتا ہے،خواہ اہلِ اسلام کاتعلق اُن سے امن کا ہو یا حرب کا۔ اس لیے صحیح اسلامی نظریہ کے مطابق، صرف دو اصطلاحیں درست ہیں—دار الاسلام اور دار الدعوہ۔ اس کے سوا جو بھی اصطلاحیں بولی گئی ہیں وہ سب میرے نزدیک اجتہادی خطا کا درجہ رکھتی ہیں۔ مثلاً دار الحرب، دار الکفر، دار الطاغوت، وغیرہ۔
جہاد کا تصور
کچھ مسلمانوں کی غلط تعبیر کے نتیجہ میں، جہاد کا تصور یہ بن گیا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے، مصلحانہ جنگ۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان دنیا میں خدا کے خلیفہ ہیں۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی نیابت میں خدا کی حکومت دنیا میں قائم کرے۔ وہ خدا کی طرف سے لوگوں کو خدا کے احکام کا پابند بنائے۔ اُن کے نزدیک اس لڑائی کا نام جہاد ہے۔جہاد کا یہ تصور بلا شبہہ بے اصل ہے۔ قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔
مصلحانہ جنگ اپنے نتیجہ کے اعتبارسے صرف مفسدانہ جنگ ہے۔ اجتماعی زندگی میں پرامن اظہار خیال کا حق تو ہر ایک کو ہے لیکن طاقت کو استعمال کرکے اصلاح کرنے کا نظریہ بین اقوامی زندگی میں ناقابل قبول ہے۔ اجتماعی یا بین اقوامی زندگی میں کوئی گروہ اپنے لیے ایک ایسا حق نہیں لے سکتا جسے وہ دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر ایک گروہ اپنے لیے اصلاحی جنگ کا حق لینا چاہے تو یقینی طورپر اسے دوسروں کو بھی اصلاحی جنگ کا یہ حق دینا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر گروہ خود ساختہ اصلاح کے نام پر دوسرے سے جنگ شروع کردے گا۔ اس کے نتیجہ میں اصلاح تونہ ہوگی البتہ اس کی وجہ سے ایک ایسا فساد برپا ہوگا جو کبھی ختم نہ ہو۔
حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی جائز صورت صرف ایک ہے، اور وہ دفاع ہے اگر ایک قوم اپنی جغرافی حد سے تجاوز کرکے دوسری قوم کے اوپرکھلا حملہ کردے تو ایسی صورت میں زیر حملہ قوم کواپنے بچاؤ میں جوابی جنگ کا حق حاصل ہے۔ اس ایک صورت کے سوا کسی بھی دوسری صورت میں متشددانہ جنگ کا کوئی جواز نہیں۔
یہ اجتماعی اصول اسلام میں بھی اسی طرح مسلّم ہے جس طرح سے وہ دوسرے نظاموں میں تسلیم کیاگیا۔ اس اجتماعی اصول کے معاملہ میں اسلام اور غیر اسلام کے درمیان کوئی فرق نہیں۔
اس سلسلہ میں ایک مسئلہ وہ ہے جو پچھلی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ پچھلا زمانہ بادشاہی زمانہ تھا۔ ساری دنیا میں ہر جگہ کچھ خاندان حکومت کرتے تھے۔ اُس زمانہ میں بادشاہ کا یہ حق سمجھا جاتا تھا کہ وہ قانون سے بالا تر ہے اور وہ جو چاہے کرے۔ اس بنا پر قدیم شاہی زمانہ میں ہر بادشاہ نے ایسے کام کئے جو اخلاقی یا قانونی اعتبار سے درست نہ تھے۔ قدیم زمانہ میں ہندستان کے مسلم بادشاہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مثلاً محمود غزنوی نے سومناتھ کے ہندو مندر کو ڈھایا اور اُس کے سونے کے ذخیرہ کو لوٹا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب نے بنارس کے ایک ہندو مندر کو ڈھایا اور اُسی جگہ مسجد تعمیر کی، وغیرہ۔
بادشاہوں کی طرف سے اس قسم کے واقعات قدیم زمانہ میں ہر ملک میں ہوئے۔ مگر وہ صرف قدیم تاریخ کا ایک حصہ بن کر رہ گئے، وہ بعدکے زمانہ میں دو قوموں کے درمیان مستقل نزاع کا سبب نہ بن سکے۔ صرف ہندستان میں ایسا ہوا کہ اس طرح کے واقعات یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مستقل طورپر تلخی کا سبب بن گئے۔ اس کے نتیجہ میں فرقہ وارانہ فساد بھی بار بار ہوئے۔ وہ قومی یکجہتی کا ماحول قائم کرنے کی راہ میں ایک مستقل رکاوٹ بن گئے۔
میرے نزدیک اس استثنائی صورت حال کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مسلم علماء اور دانشوروں نے ہندستان کی مسلم حکومتوں کو اسلامی حکومت کا نام دے دیا۔ وہ اس کو اسلام کی تاریخ کا ایک باب سمجھنے لگے۔حالاں کہ ان حکومتوں کی حیثیت صرف کچھ مسلم خاندانوں کی حکومت (dynasty) کی تھی۔ اُن کو اُصولی اعتبار سے اسلام کی حکومت بتانا درست نہ تھا۔ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی بنا پر ایسا ہوا کہ جو واقعات ایک مخصوص مسلم خاندان کی حکمرانی سے تعلق رکھتا تھا وہ اسلام کے نام کے ساتھ جُڑگیا۔
اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی بنا پر یہ شدید غلطی ہوئی کہ مسلمان ان حکمرانوں کے دورِ حکومت کو اپنے لیے اسلامی فخر کے طور پر لینے لگے۔ وہ اُس کوغلبۂ اسلام کی علامت سمجھنے لگے۔دوسری طرف ہندوؤں میں وہ نظریہ پیدا ہوا جس کو تاریخی غلطیوں (historical wrongs) کی اصلاح کہا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ واضح طورپرباہمی تلخی کی صورت میں نکلا۔ مسلمانوں نے جب اس کو اپنا فخر بنایا تو شعوری یا غیر شعوری طورپر وہ اُن کی مذہبی تاریخ کا ایک مقدّس حصہ بن گیا اور دوسری طرف ہندوؤں نے اُس کو تاریخی غلطی سمجھ کر اُس کی اصلاح کی کوشش شروع کردی۔
میرے نزدیک اس معاملہ میں دونوں فریق غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مسلمان کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس تاریخ کو مذہبی حیثیت دینے کی بنا پر اُس پر نظر ثانی کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف ہندوؤں کی غلطی یہ ہے کہ وہ گذری ہوئی تاریخ کو بھولنے پر تیار نہیں۔ وہ ماضی کی غلطیوں کی تصحیح پر اصرار کررہے ہیں، خواہ اُس کے نتیجہ میں حال کے امکانات برباد ہوکر رہ جائیں۔
میرے نزدیک اس معاملہ میں دونوں فریقوں کو حقیقت پسند بننا چاہئے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ پچھلے مسلم بادشاہوں کو اسلامی حاکم کا درجہ نہ دیں بلکہ اُن کی حکومت کو صرف ایک خاندان کی حکومت (dynasty) قرار دیں۔ وہ ان مسلم بادشاہوں کی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی کارروائیوں کا انکار (disown) کریں، وہ کھلے طورپر اُن کی مذمت کریں، خواہ، وہ محمود غزنوی ہو یا اورنگ زیب یا کوئی اور۔
دوسری طرف ہندوؤں کو چاہئے کہ وہ مضٰی ما مضی (gone is gone) کے اُصول پر ماضی کو بھلا دیں۔ وہ اس معاملہ میں جذباتی طریقہ کو چھوڑ کر حقیقت پسندانہ انداز اختیار کریں۔ ہندوؤں کو جاننا چاہئے کہ تاریخی غلطیاں ہمیشہ ہوئی ہیں مگر کوئی بھی کبھی تاریخی غلطیوں کی تصحیح نہ کرسکا۔ تاریخی غلطیوں کی تصحیح کا نظریہ بلاشبہہ غیر دانش مندانہ ہے۔ یہ ماضی کی تصحیح کے نام پر حال کی تخریب ہے۔ یہ فطرت کے اُصول کے خلاف ہے۔ ایسے لوگ ماضی کو پانے کے نام پر اپنے حال اور مستقبل کو بھی کھو دیتے ہیں۔
بد قسمتی سے ہندستان کے حق میں یہ بات پوری طرح واقعہ بن گئی ہے۔ جن ملکوں نے اپنے ماضی کو بھُلا کر اپنے حال کی تعمیر کرنا چاہا، اُنہوں نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ اس کی ایک مثال جاپان ہے۔ جاپان نے امریکہ کی غلطیوں کی تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان آج ایک اقتصادی سُپر پاور بنا ہوا ہے۔ دوسری مثال ہندستان کی ہے۔ ہندستان میں ماضی کی غلطیوں کی تصحیح کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہندستان صرف ایک پچھڑا ہوا ملک بن کر رہ گیا۔
قومی ترقی کی لازمی شرط یہ ہے کہ قومی ترقی کے سوال کو اصل بنایا جائے اور بقیہ تمام چیزوں کو سیکنڈری حیثیت دے دی جائے۔ لوگوں میں یہ سوچا سمجھا ذہن موجود ہو کہ اصل اہمیت کی چیز یہ ہے کہ قومی ترقی کا عمل کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے۔ اس کے سوا جو جذباتی مسائل ہیں یا اور جو ذاتی مفروضات ہیں وہ اگر قومی ترقی کے عمل میں رکاوٹ ڈالے بغیر حاصل ہوتے ہوں تو ٹھیک، ورنہ وہ ہمیں منظور نہیں۔ یہی واحد طریقہ ہے جس کی پیروی کرکے ملک کو حقیقی معنوں میں ترقی دی جاسکتی ہے، اس کے بغیر امن ممکن نہیں۔
مشہور قصہ ہے کہ ایک قاضی کے پاس ایک کیس آیا۔ ایک نوزائیدہ بچہ تھا اور دو عورتیں یہ دعویٰ کررہی تھیں کہ وہ اُس کی ماں ہے اور اس بچہ کو اس کے حوالہ کردینا چاہئے۔ مگر دونوں میں سے کسی کے پاس بھی کوئی قانونی ثبوت موجود نہ تھا۔ یہ قاضی کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ آخر کار اُس نے یہ حکم دیا کہ بچہ کے جسم کو بیچ سے کاٹ کر دو ٹکڑے کردیئے جائیں اور پھر اُس کا ایک ٹکڑا ایک عورت کو دیاجائے اور اُس کا دوسرا ٹکڑا دوسری عورت کو دیا جائے۔
قاضی نے جب اپنا یہ حکم سنایا تو جو عورت بچہ کی ماں ہونے کی فرضی دعویدار تھی اُس پراس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مگر جو عورت بچہ کی حقیقی ماں تھی وہ چیخ اٹھی۔ اُس نے کہا کہ بچہ کو مت کاٹو۔ اُس کو تم دوسری عورت کے حوالہ کردو۔ یہی محبت کا حقیقی معیار ہے۔ جن لوگوں کو ملک سے حقیقی محبت ہے اُنہیں چلّا کر کہنا چاہئے کہ ہم دیش کی تباہی کو دیکھ نہیں سکتے۔ پچھلی تاریخ میں جو کچھ ہوا اُس کو ہم بھلاتے ہیں تاکہ حال کے مواقع کو بھر پور طورپر استعمال کیا جاسکے اور ملک کا ایک نیا شاندار مستقبل پیدا کیا جاسکے۔
قومی زندگی میں امن اور اتحاد کا اصول صرف toleration کی بنیاد پر ممکن ہے۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ مختلف افراد اور مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات پیداہوں۔ فرق اور اختلاف زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ اس لئے فرقہ وارانہ زندگی میں اعتدال کا ماحول فرق اور اختلاف کو مٹا کر قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ مقصد جب بھی حاصل ہوگا تحمل اور ٹالرنس کی بنیاد پر حاصل ہوگا۔
حقیقت یہ ہے کہ اختلاف کو مٹانے کی کوشش کسی انسانی گروہ کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ فطرت کے عالم گیر قانون کے خلاف ہے۔ کوئی بھی شخص یا گروہ اتنا طاقت ور نہیں کہ وہ فطرت سے لڑکر جیت سکے۔ اس لیے حقیقت پسندی کا تقاضہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں برداشت کے اصول کو اپنایا جائے نہ کہ ٹکراؤ کے اصول کو۔ اختلاف کو گوارا کرو تاکہ اتحاد قائم ہو۔ کیوں کہ اختلاف کو مٹا کر اتحاد قائم کرنے کا منصوبہ تو سرے سے ممکن ہی نہیں۔